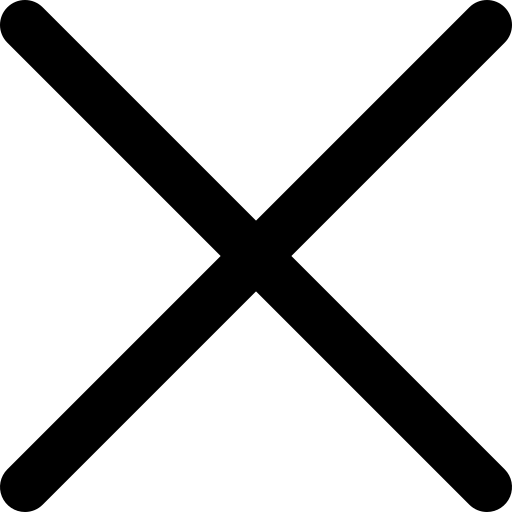ڈاکٹر عمیر منظر
شعبہ اردو
مولانا آزاد نیشنل اردو یونی ورسٹی لکھنؤ کیمپس۔لکھنؤ
اردوزبان کے بارے میں جو غلط فہمیاں رائج ہیں ان میں سب سے بڑی غلط فہمی اس زبان کو غیر ملکی قرار دیا جانا ہے۔اسے مغل حکمرانوں سے بھی جوڑ کرکے دیکھاجاتا ہے جو سراسر غلط ہے۔یہ بات بھی بغیر ثبوت کے پھیلادی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔گذشتہ دنوں مہاراشٹر کے اکولہ ضلع میں پٹورمیونسپل کونسل کی عمارت کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کے لے کر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے بہت سی غلط فہمیوں کو دور کردیا ہے۔عدالت نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ ”یہ غلط فہمی ہے کہ اردو ہندوستان کے لیے اجنبی ہے۔اردو وہ زبان ہے جو ہماری ہی سرزمین پر پیدا ہوئی ہے“۔عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی واضح کردیا کہ یہ زبان نہ کسی قوم کی ہے نہ کسی علاقے کی اور نہ یہ کسی مذہب کی زبان ہے۔جسٹس سدھانشودھولیااور جسٹس کے ونود چندرن کی بنچ نے یہ فیصلہ سنایا جس کی گونج پورے ملک میں سنی گئی اور انصاف پسند شہریوں نے نہ صرف اسے پسند کیا بلکہ اس حقیقت بیانی کی داد بھی دی۔
واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان سے متعلق غلط فہمی پھیلانے والوں میں جہاں سیاست دانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہیں اس کو ہوا دینے میں امرت رائے اور گیان چند جین کا بھی ہاتھ رہا ہے۔امرت رائے نے جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے مواد کی فراہمی کا کام گیان چند جین نے کیا ہے (مرزا خلیل احمد بیگ کی مرتبہ کتاب ”گیان چند جین کے خطوط بنام مرزا خلیل احمد بیگ“۔میں ملاحظہ کرسکتے ہیں)امرت رائے کے بارے میں مرزا خلیل احمد بیگ نے لکھا ہے کہ انھوں نے جو کچھ لکھا اس میں تحقیق سے زیادہ لسانی عصبیت شامل ہے۔انھوں نے اردو کے آغاز کے سلسلے میں درست لسانی تناظر کے بجائے ہندی کے ز مانی تقدم کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کی۔اسی لیے مرزا خلیل احمد بیگ نے امرت رائے ’کے سوچنے کے اندازکو تحقیقی سے زیادہ متعصبانہ‘قرار دیا ہے۔مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب لسانی تناظر میں اس بحث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔
ہند آریائی زبانوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اردو کا تعلق شورسینی اپ بھرنش سے ہے۔ جو شورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی ہے۔ شورسینی پراکرت قدیم ہند آریائی دور کے مدھیہ دیشہ سے تعلق رکھتی ہے۔ 1000عیسوی میں مختلف اپ بھرنشوں سے جدید ہند آریائی زبانوں کا ارتقا عمل میں آتا ہے شور سینی اپ بھرنش سے مختلف بولیاں جنم لیتی ہیں۔ انھیں بولیوں میں ایک کا نام کھڑی بولی ہے۔ یہی کھڑی بولی جو نواح دہلی میں بولی جاتی تھی اردو کی اساس اور بنیاد قرار پاتی ہے۔ 1200سے 1400ء کا زمانہ اردو کا تشکیلی دور کہلاتا ہے اور یہی ز مانہ گجرات اور دکن میں اس زبان کے پھلنے پھولنے اور بڑھنے کا ہے اس کے حق میں ایک ایسی فضا بن گئی تھی کہ یہ ان علاقوں میں رابطے کی زبان بن کر ترقی کرنے لگی۔اور بہت جلد صوفیائے کی خانقاہوں سے لے کر بادشاہوں کے درباروں تک اردو کا چلن ہوگیا۔پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ نے اپنے ایک انٹر ویو میں کہا ہے کہ اردو ہندوستان میں مغلوں کی حکمرانی سے کئی سو سال قبل معرضِ وجو د میں آچکی تھی۔
اردو کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اردولفظ کوبطور زبان پہلے ہندوی،ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور ریختہ کہا گیا۔ جنوب میں اسے دکنی کہا گیااورشمالی ہند میں عام طور پر اسے ریختہ اور ہندی کا نام بطور زبان دیا گیا۔ البتہ انیسویں صدی کے وسط تک آتے آتے ریختہ پر اردو کو ترجیح دی جانے لگی یہا ں تک کہ زبان کے نام کے طور پر ریختہ کا استعمال کم ہونے لگا۔البتہ بول چال کی زبان کو اردو کہا جانے لگا۔ شمس الرحمٰن فاروقی نے لکھا ہے کہ بطور زبان لفظ ”اردو“ پہلی بار 1780ء کے آس پاس استعمال ہوا۔ انھوں نے مصحفی کے ایک شعر کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ فاروقی نے مختلف مثالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ”زبان کے نام کے طورپر لفظ اردو کا استعمال اٹھارہویں صدی عیسوی کے ربع آخر کے پہلے نہیں ملتا“(اردو کا ابتدائی زمانہ ص:16)شمس الرحمن فاروقی، مصحفی کے درج ذیل شعر سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔
البتہ مصحفی کو ہے ریختے میں دعوی
یعنی کہ ہے زباں داں اردوکی وہ زباں کا
اغلب ہے کہ یہاں لفظ ”اردو“سے”شاہجہاں کا شہر“مراد ہے،نہ کہ ”اردو زبان“۔ فقرہ”اردو کی زبان“کے معنی وہ زبان سمجھنا جس کا نام ”اردو“ہے،اسی وقت صحیح ہوگا جب یہ یقینی ہوکہ لفظ ”اردو“کو ”شاہ جہاں آباد“کے معنی میں نہیں استعمال کیاگیا ہے۔جیسا کہ ہم آیندہ دیکھیں گے،شمال کے لوگ عرصہئ دراز تک ”اردو“کو ”شاہجہاں آباد“کے معنی میں بولتے تھے۔اور ”ز بان اردو“سے بعض اوقات ”فارسی“بھی مراد لی گئی ہے۔خیر،مصحفی کے دیوان چہارم میں (مرتبہ تقریباً 1796ء)میں جو استعمال ہے وہ صاف طور پر ”اردو ز بان“کے معنی میں ہے۔
ہرجائے گوش چشم بناناک کان کو
اپنی زبان سمجھے ہیں اردو زبان کو
اردو کے آغاز کے سلسلے میں جو نظریے پیش کیے گئے ان میں سندھ،پنجاب،نواح دہلی اور دکن میں پیدا ہونے کا نظریہ شامل ہے۔بعض عالموں نے برج بھاشا،کھڑی بولی اور ملواں زبان ہونے کا نظریہ پیش کیا۔لکھنے والوں میں وہ بھی ہیں جنھو ں نے کسی ٹھوس بنیاد اور دلیل کے بغیر اردو زبان کے آغاز کو بیان کیا ہے اسی وجہ سے ان کی باتیں اب محض تاریخ کا حصہ ہیں۔ لسانی ماہرین نے اردو کے آغاز کے سلسلے میں ٹھوس دلائل کے ساتھ لسانی بنیادوں پر جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی۔اردو کے آغاز کے سلسلے میں بعض مستشرقین نے بھی قلم اٹھایا ان میں ٹی گراہم بیلی،جارج ابراہم گریرسن،جان بیمزکے نام شامل ہیں۔اردو میں لسانی مباحث کی ابتدا کے سلسلے میں سید انشاء اللہ خاں انشا کا بھی نام لیا جاتا ہے۔’دریائے لطافت (1807)میں سید انشاء اللہ خاں انشا نے برج بھاشا کے میل جول کا نتیجہ قراردیا۔ محمد حسین آزاد کے نظریے کی بھی بڑی دھوم رہی ہے۔چونکہ برج کا علاقہ اور بھاشا دونوں اہمیت کے حامل رہے ہیں۔بعض لوگوں نے برج بھاشا کو اردو کی ماں کے طورپر پیش کرکے بھی غلط فہمی پھیلائی جس سے اس نظریے کو شہرت ملی۔ محمود شیرانی،شوکت سبزواروی اور مسعود حسین خاں نے برج بھاشا کے نظریے کی نہ صرف تردید کی بلکہ لسانی و تحقیقی بنیادوں پر اسے یکسرغلط بھی ٹھہرایا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی ہندی کی بولیوں میں برج بھاشا کو مقبولیت حاصل تھی۔آزاد چونکہ لسانی ماہر نہیں تھے اس لیے وہ بولیوں کے فرق کو نہیں سمجھ سکے جیسا کہ مسعود حسین خاں اور مرزا خلیل احمد بیگ نے لکھا ہے۔گیان چند جین کہناہے کہ اردو کا آغاز کھڑی بولی یا ہندوستانی کے آغاز کے سوا کچھ نہیں ہے۔انھوں نے اس بات پربھی زور دیا ہے کہ اردو جس بولی سے نکلی ہے، پہلے اس کا تعین کیا جائے، اس کے بعد کھڑی بولی کے اردو روپ کی تحقیق کی جائے کیونکہ ان کے نزدیک بول چال کی حد تک کھڑی بولی،اردو اور ہندی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں پیدا ہونے کا نظریہ پیش کیا۔پنجابی اور قدیم اردو زبان کا بغور مطالعہ نیز دونوں زبانوں میں مستعمل بہت سے ایسے الفاظ،مصادر اور صیغوں کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا جو ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔نصیر الدین ہاشمی نے اردوکے دکن میں پیدا ہونے کا خیال ظاہر کیا۔انھوں نے تحقیق کی روشنی میں اردو کے ابتدائی مراحل اوربعض تاریخی تناظر کی روشنی میں اس مسئلہ کو دیکھا۔البتہ ماہرین لسانیات کا خیال ہے کہ یہ اسی طرح کی کوشش ہے جس طرح سید سلیمان ندوی نے سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ پیش کیا تھا۔ پروفیسر مسعود حسین خاں نے اس نظریے کی سخت تردید کی اور کہا کہ دکنی کوئی علاحدہ زبان نہیں ہے بلکہ یہ اردو کا ایک مقامی نام ہے۔
مسعود حسین خاں نے دہلی اور نواح دہلی میں اردو کے پیدا ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ان کے بقول کھڑی بول اردو کی محکم اساس ہے اور انھوں نے لسانی اور تاریخی تناظر میں اپنی بات کوپایہئ ثبوت تک پہنچایا۔مسعود حسین خاں نے لکھا ہے کہ شہر دہلی تین بولیوں کے سنگم پر واقع ہے اور اردو کے ارتقا میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف ز مانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ان کا نظریہ ٹھوس لسانیاتی بنیادوں پر قائم ہے اس لیے اس کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا جاسکا ہے۔ دراصل انھوں نے امیر خسرو کا فقرہ ’زبان دہلی و پیرا منش‘ سے فائدہ اٹھایا۔انھوں نے نہ صرف ان بولیوں کا تجزیہ کیا بلکہ دکنی اور پنجابی کی لسانی خصوصیات کو بھی واضح کیا۔ مسعود حسین خاں نے کا خیال ہے کہ ”اردو کا نقطہ آغاز 1193میں مسلمانوں کا داخلہ دہلی ہے“اس کے بعد ہی عربی و فارسی کے لسانی اثرات نواح دہلی کی بولیوں میں سرایت /داخل ہوتے ہیں اور ان بولیوں میں سب سے زیادہ اثرات کھڑی بولی نے قبول کیے۔انھوں نے 1200سے 1400کے عرصے کو دور اول شمار کرتے ہیں۔یعنی اسے اردو کا تشکیلی دور قرار دیا جاسکتا ہے۔پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ نے اس دور کا تجزیہ کرتے ہوئے جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کے بعض نکات اس طرح ہیں۔ ’اردو کے قدیم نام ہندوی کے پہلے مستند شاعر سمجھنے جانے والے امیر خسرو دہلوی کا تعلق اسی دور سے ہے۔صوفیائے کرام کے اقوال و ملفوظات زیادہ تر اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔نواح دہلی کی اہم بولی کھڑی جس پر اردو کا دارومدار ہے اس میں عربی و فارسی الفاظ کا نفوذ اسی دور میں شروع ہوا نیز اردو کے ہندی اور ہندوی نام اسی دور میں پڑتے ہیں۔ ہندوی،ہندی یا زبان دہلی جو کہ اسی دور میں دکن پہنچتی ہے جہاں وہ ارتقا کی منزلیں طے کرتی ہے‘۔خلیل بیگ کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے مسعود حسین خاں فتح دہلی(1193ء)کو اردو کا نقطہ آغاز مانتے ہیں۔اردوکے آغاز کایہی نظریہ سب سے قابل قبول ہے کیونکہ اسے کسی ٹھوس لسانی بنیاد پر اب تک رد نہیں کیا جاسکا ہے۔
چونکہ اردو کو بعض لوگوں نے لشکری زبان بھی کہا ہے۔یہاں یہ ذکر ضر وری ہے کہ یہ بات محض ایک افواہ اور غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ نے اس خیال کا تعاقب اپنے ایک انٹرویو میں اس طرح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:
اردو کو لشکری زبان کہنا، اردو زبان کی تاریخ سے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ضرور ہے،لیکن اس سے مراد صرف لشکر یا معسکر یعنی فوجی چھاؤنی نہیں ہے۔ اردو کے معنی شہر، قلعہ اور دربار کے بھی ہیں، چنانچہ’زبانِ اردوئے معلیٰ یا’زبانِ اردو‘ سے لشکرکی زبان مراد لینا قطعی درست نہیں۔ ان فقروں سے شہر(=شہرِ شاہجہان آباد /شہرِ دہلی)کی زبان مراد ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی کے خیال کے مطابق ’زبانِ اردوئے معلی‘ کا فقرہ پہلے فارسی کے لیے مستعمل تھا، پھر بہت بعد میں یعنی اٹھارھویں صدی کے اواخر میں یہ اردو کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ کثرت ِاستعمال سے ”زبان“اور ”معلی“دونوں گر گئے۔اردو کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مغل حکمرانوں کے لشکر میں یا لشکر کے بازار میں پیدا ہوئی، اس لیے بھی درست نہیں کہ اردوہندوستان میں مغلو ں کے دورِ حکمرانی سے کئی سو سال قبل یعنی بارھویں صدی عیسوی میں معرضِ وجود میں آچکی تھی۔کسی زبان کی تشکیل سماجی اور تہذیبی ضروریات کے ماتحت عوامی سطح پر عمل میں آتی ہے، نہ کہ لشکری اور فوجی سطح پر۔ لشکر اور فوج کے لوگ تو ہمیشہ عوام سے دوری ہی بنائے رکھتے ہیں۔ انھیں عوام سے رابطے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے، لہٰذا وہ کسی زبان کو معرضِ وجود میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اردو کو لشکری زبان کہنا نو آباد کاروں کی جان بوجھ کر پھیلائی ہوئی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔(ماہنامہ ایوان اردو،نومبر 2019ص 30)
ان معروضات سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اردو کے سلسلے میں رائج غلط فہمیوں کا علمائے ادب نے ہمیشہ تدارک کیا ہے اور اس زبان کے آغاز کے سلسلے میں طویل طویل بحثوں کے بعد بھی کسی نے اسے غیر ملکی زبان نہیں قرار دیا ہے بلکہ یہ ہند آریائی زبان ہے جو نواح دہلی میں پیدا ہوئی اور یہاں کے تمام باشندوں نے بلا تفریق مذہب و قوم اس کو اختیار کیا۔